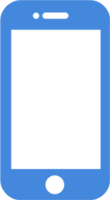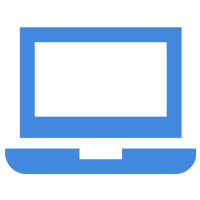قرآن اور علمِ جدید (یونی کوڈ فارمیٹ)
مارکس کا غلط فلسفہ
اسلام اوراشتراکیت کا فرق
انسانی مرحلہ کے ارتقاء اور اقتصادی مساوات کے دو مجرد تصورات کے علاوہ مارکس کا باقی تمام فلسفہ اسلام کے اساسیات کے ساتھ متعارض ہوتا ہے اور ان دو تصورات کی صداقت بھی مارکس کے فلسفہ میں آ کر بری طرح سے مسخ ہو گئی ہے یہاں تک کہ یہ کہنا چاہیے کہ مارکسی ان تصورات کو جس طرح سے مانتے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ نہ تو انسانی مرحلہ میں ارتقاء اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مارکس نے فرض کیا ہے اور نہ ہی اقتصادی مساوات اس طریق سے قائم ہوتی ہے جس طریق سے مارکس اسے قائم کرنا چاہتا ہے۔
ایک غلط خیال
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روسی اشتراکیت ایک اقتصادی نظام ہے جس کا منشا فقط یہ ہے کہ وسائل پیداوار کو ریاست کے سپرد کر کے افراد کے درمیان دولت کی مساوی تقسیم کو ممکن بنایا جائے یا ان حضرات کو معلوم نہیں کہ روس کا اقتصادی نظام ایک ایسے فلسفہ پر مبنی ہے جس میں خدا‘ روح‘ اخلاق اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں اور یا اگر معلوم ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس فلسفہ سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو فقط روس کے اقتصادی نظام کو لینا چاہتے ہیں۔
روسی فلسفہ اور روسی نظام لازم و ملزوم ہیں
دراصل یہ نقطۂ نظر حد درجہ غلط ہے ۔ روس کا اقتصادی نظام مارکس کے فلسفہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن نہیں کہ آپ مارکس کے اقتصادی نظام کو تو لے لیں اور مارکس کے فلسفہ سے کنارہ کش رہیں۔ آپ مجبور ہیں کہ یا دونوں کو لے لیں یا دونوں کو چھوڑ دیں۔ روسی اقتصادی نظام ایک تعمیر ہے جو مارکس کے نظریہ انسان و کائنات پر مبنی ہے جب آپ بنیاد کو ہٹا دیں گے تو تعمیر خود بخود گر جائے گی۔
روس کا اقتصادی نظام فقط وسائل پیداوار کے ریاستی قبضہ یا دولت کی مساوی تقسیم کا نام نہیں۔ بلکہ وہ ایک ایسا اقتصادی نظام ہے جو انسان کی ساری زندگی کو ایک خاص طریق سے متعین کرتا ہے‘ اسے برپا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے آپ کو انسان اور کائنات کے ایک خاص نظریہ یا ایک خاص مذہب پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ ایک خاص قسم کے نظامِ تعلیم‘ نظامِ اخلاق‘ نظامِ قانون اور نظامِ سیاست کو جاری کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اقتصادی نظام ایک پورے نظامِ حیات کا جزو ہے۔باقی سارا نظامِ حیات اسے ایک خاص شکل میں متعین کرتا ہے۔ اور یہ خود باقی سارے نظامِ حیات کو متعین کرتا ہے اور یہ سارا نظامِ حیات صرف ایک بنیاد پر قائم ہے اور وہ مارکس کا فلسفہ ہے جو ساری کائنات کا ایک نظریہ ہے اور ہر روسی فرد کی ساری زندگی اس کے مطابق تشکیل پاتی ہے۔ لہٰذا کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم روس کے اقتصادی نظام کو اس کی پوری وحدت سے الگ کر کے لے لیں‘ ایسا کرنے سے روسی اقتصادی نظام مردہ ہو جائے گا اور جو چیز ہمارے ہاتھ آئے گی وہ روسی اقتصادی نظام نہیں ہو گا بلکہ کوئی اور اقتصادی نظام ہو گا جو انسان اور کائنات کے متعلق ہمارے اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو گا اور پھر ہمارا اپنا نظامِ تعلیم‘ نظامِ قانون‘ نظامِ اخلاق اور نظامِ سیاست اسے سہارا دے رہا ہو گا اور یہ اقتصادی نظام روس کے اقتصادی نظام کے مقابلہ میں اتنا ہی اچھا یا برا ہو گا جتنا کہ انسان اور کائنات کے متعلق ہمارا اپنا نقطۂ نظر صحیح یا غلط ہو گا۔
انسانی زندگی کی وحدت
انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے وہ الگ الگ حصوں کا مجموعہ نہیں اور نہ ہی الگ الگ حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ایک ہی قوت سے متعین ہوتا ہے اور وہ قوت کائنات کے متعلق انسان کا نظریہ ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی کا ہر پہلو تمام دوسرے پہلوؤں میں شامل اور شریک ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو فقط اقتصادی مقاصد رکھتا ہو۔ ہر شخص بیک وقت اقتصادی ‘ اخلاقی‘ سیاسی‘ تعلیمی اور قانونی مقاصد اور افکار و آراء رکھتا ہے اور یہ تمام مقاصد اور افکار و آراء چونکہ اس کے نظریۂ زندگی سے پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک وحدت اور ہم رنگی اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اقتصادی مقاصد وہی ہوں گے جو اس کا نظریۂ زندگی چاہے گا۔
روسی نظام کی وحدت
روسی نظامِ حیات چونکہ انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہے وہ ایک جسمِ حیوانی کی طرح ایک وحدت ہے۔ اس کا اقتصادی حصہ مردہ ہونے کے بغیر اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کتے کے جسم سے اس کی ایک ٹانگ کاٹ لیں تو ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ رہے گی یا شتر مرغ کی ایک ٹانگ بن کر اپنا کام کرتی رہے گی۔ روسی اقتصادی نظام کی مخصوص نوعیت کو سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرلینا کافی ہے کہ اگر روسیوں کی باقی زندگی کا کوئی حصہ مثلاً اُن کا نظامِ تعلیم یا نظامِ سیاست یا نظامِ قانون یا نظامِ اخلاق اُس سے بجبر الگ کر دیا جائے تو روسی اپنے اقتصادی نظام کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔
قابل غور بات
ان حقائق کی بنا پر بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو روسی اقتصادی نظام سے اس لیے شغف رکھتے ہیں کہ وہ اقتصادی مساوات کی امید دلاتا ہے‘۔ یہ دیکھیں کہ آیا وہ مارکس کے نظریۂ کائنات کو جو لازماً اس کے ساتھ آئے گا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر یہ نظریۂ کائنات مغالطہ آمیز ‘غلط اور بے ہودہ ہو تو یقینا وہ اسے قبول نہیں کریں گے اور حقائق خود بتاتے ہیں کہ مارکس کا نظریۂ کائنات درحقیقت ایسا ہی ہے۔
ایک عبث اُمید
ہم مان لیتے ہیں کہ روسی اقتصادی نظام کا مقصد اقتصادی مساوات کا قیام ہے لیکن جو نظام دہریت پر مبنی ہو اس سے اقتصادی مساوات کی توقع عبث ہے۔ اقتصادی مساوات کی خواہش دوسرے انسانوں کی محبت سے پیدا ہوتی ہے اور دوسرے انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک جزو ہے جس کے سامنے سب انسان برابر ہیں اور سب کو برابر کا حق حاصل ہے کہ اس کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔
مساوات کی لازمی شرط
دوسرے انسانوں کی محبت اس وقت تک آزادانہ اظہار نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ محبت جس کے اندر یہ ایک جزو کی حیثیت رکھتی ہے آزادانہ طور پر اظہار نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اقتصادی مساوات چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ فرد کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کریں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ترقی پا کر نہایت قوی ہو جائے اور یہ تعلیم و تربیت ہمیں صرف اسلام سے حاصل ہو سکتی ہے۔
مارکس نے اقتصادی مساوات کا تصور مذہب سے لیا ہے لیکن اس نے حقائق کو غلط طور پر پیش کر کے اسے ایک مادیاتی فلسفہ میں داخل کر دیا ہے حالانکہ وہ ایک مادیاتی فلسفہ کا جزو نہیں بن سکتا اگر انسانی افراد اس دنیا کی نعمتوں کو آپس میں برابر طور پر تقسیم کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں تو صرف انصاف‘ نیکی اور صداقت ایسی اقدار کے لیے جن پر مذہب زور دیتا ہے اور کسی دوسری غرض کے لیے نہیں۔
تعارض
کائنات کا مادیاتی نظریہ جو کارل مارکس اپنے متبعین پر ٹھونستا ہے ایک ایسی ذہنیت پیدا کرتا ہے ‘جو اقتصادی مساوات کی خواہش کے ساتھ اندرونی طور پر متعارض ہوتی ہے‘ کیونکہ اقتصادی مساوات کی خواہش درحقیقت خدا پرستی کا ایک جزو ہے۔ مارکس اس خواہش کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے اور اس طرح فرد کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف سے تو وہ فرد کو اقتصادی مساوات پر مجبور کرتا ہے اور دوسری طرف سے وہ اسے اس روحانی تسلی اور دلی اطمینان سے محروم کرتا ہے جو ایسی مساوات کا صرف ایک ہی انعام ہے۔
ذہنی مجادلہ
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرد کے دل کی گہرائیوں میں ایک ذہنی مجادلہ اور ایک پابندی اور مجبوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جس نسبت سے مارکسی اپنے فلسفہ پر زور دیتے ہیں اور خدا پرستی کے جذبہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اُسی نسبت سے یہ ذہنی مجادلہ اور یہ پابندی اور مجبوری کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔
مذہب کی برکت
روس میں اشتراکیت کو اس وقت تک جو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ روسیوں نے ابھی مذہب کی اس روحانی اور اخلاقی تعلیم کو نہیں بھلایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھو۔لیکن اب جوں جوں وقت گزرتا جائے گا روس کے لوگ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے اپنے آباؤ اجداد کے مذہبی احساس سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بات بعض لوگوں کو تعجب انگیز معلوم ہو گی لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر روس میں اشتراکیت زندہ ہے تو اُسی مذہبی احساس کی برکت سے جسے وہ کچلنا چاہتی ہے لیکن جس حد تک وہ اس احساس کو کچلتی جائے گی اُسی حد تک اپنی قبر کھودتی جائے گی۔
احسان ناشناسی
مارکسی کہتے ہیں کہ مذہب سے اُن کی دشمنی کا سبب یہ ہے کہ مذہب ذاتی ملکیت اور جلبِ منفعت (Exploitation)کا حامی ہے لیکن درحقیقت یہ سوشلسٹوں کی احسان ناشناسی اور محسن کشی ہے کیونکہ حقوق ملکیت کا احترام (مثلاً یہ کہ دولت ِ آفریدہ میں سرمایہ دار کا حق کتنا ہے اور مزدور کا کتنا) جو اشتراکیت کی بنیاد ہے مذہب ہی نے سکھایا ہے اور اشتراکیت صرف اس دعویٰ کی بنا پر لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے کہ وہ انصاف کرنے اور ان حقوق کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچانے کا بیڑہ اٹھاتی ہے۔
مذہب نے بالخصوص اسلام نے جس حد تک شخصی ملکیت کی حمایت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ افراد ایک دوسرے کی ذاتی ملکیت کو غصب نہ کریں کیونکہ اس طرح سے جماعت میں بدنظمی اور انتشار پیدا ہوتا ہے اور ذاتی ملکیت بھی جوں کی توں رہتی ہے۔ صرف اس کے مالک ناجائز طور پر بدل جاتے ہیں ۔ لیکن اسلام شخصی ملکیت کو جماعتی ملکیت بنانے کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ حمایت کرتا ہے۔
اقتصادی مساوات مقصدِحیات نہیں
مارکسیوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اقتصادی مساوات کو زندگی کا آخری مقصد اور مدعا قرار دیتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی مساوات بذاتِ خود انسان کی زندگی کا مقصد نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد خود شعوری کی کامل نشوونما یا جذبۂ حسن کا کامل اظہار ہے جو طلب جمال حقیقی سے ممکن ہوتا ہے اور اقتصادی مساوات انسان کے اس مقصد کی جستجو کے راستہ پر خود شعوری کے ضمنی حاصلات کے طور پر وجود میں آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ ضمنی حاصلات خود شعوری کے تمام حاصلات کی طرح اس کی آئندہ کی ترقی اور نشوونما کے امدادی وسائل کا کام بھی دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے دل میں‘ جو سمجھتے ہیں کہ پہلے اقتصادی مساوات کو روسی اشتراکی طریقہ سے حاصل کر لینے دیجیے پھراسلام کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا ‘کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں پھر اس بات کا اعادہ کر دینا ضروری ہے کہ اگر اقتصادی مساوات اس طرح سے وجود میں آئے تو وہ شخصیت انسانی کے ارتقاء کے لیے حد درجہ ضرر رساں ہونے کے علاوہ خود قائم نہیں رہ سکتی۔
زمین و آسمان کا فرق
جب اقتصادی مساوات خود مقصدِ حیات قرار پائے تو زندگی کی تمام اقدار اس کے تابع ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ مقصدِ حیات کے تتبع کے دوران میں ایک ضمنی فائدہ کے طور پر حاصل ہو تو مقصدِ حیات کی خدمت گزار بن کر موجود رہتی ہے۔ اس سے فرد اور جماعت کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے ۔ معاشرہ کی دو قسمیں ہیں جو ان دو مقاصد کے ماتحت وجود میں آتی ہیں ‘اقدار حیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔اگر ایک معاشرہ مشرق کو جاتا ہے تو دوسرا مغرب کو۔ اگر ایک انسان کے انتہائی عروج اور کمال کی طرف جاتا ہے تو دوسرا اس کے انتہائی انحطاط اور زوال کو۔ اور پھر ان میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اندرونی طور پر اس معاشرہ کی مزاحمت کرتی ہے جو اقتصادی مساوات کو مقصدِ حیات قرار دیتا ہے۔ یہ مزاحمت رفتہ رفتہ بڑھتی اور آشکار ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ معاشرہ کو برباد کر کے اپنی تشفی کے لیے راستہ صاف کرتی ہے۔
مارکس کی بنیادی غلطی
اس کتاب کے حصہ اول میں مارکس اور اینگلز کے جو حوالے نقل کیے گئے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مارکس کے سارے فلسفہ کا بنیادی یا مرکزی تصور جس سے اُس کی باقی ماندہ تمام غلطیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا یہ تصور ہے کہ نظریات یا آدرش(Ideals) یا معتقدات(Creeds) اقتصادی حالات سے پیدا ہوتے ہیں اور نظریات اور معتقدات میں وہ انسان کی ان تمام سرگرمیوں کو شامل کرتا ہے جو جذبۂ حسن کی تشفی سے یا نظریات اور معتقدات کی جستجو سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً مذہب‘ اخلاق‘ سیاست‘ قانون‘ علم‘ ہنر(Art)‘عقل(Reason)سائنس اور فلسفہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو نظریاتی شکلوں(Idealogical Forms)کا نام دیتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ ان سرگرمیوں کو شعور(Consciousness)یا مشتملاتِ شعور(Contents of Consciousness)کی اصطلاح سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ لفظ شعور کا یہ استعمال مارکس کا اپنا ہے اور حکماء نے اس لفظ کو کبھی ان معنوں میں استعمال نہیں کیا اور ہماری اس کتاب میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔
مارکس کا اعتراف
مارکس خود مانتا ہے کہ:
’’جو خیال میرے تمام غور و فکر کی راہنمائی کرتا رہا ہے یہ ہے کہ نظریات اور معتقدات اقتصادی حالات کا نتیجہ ہیں‘‘۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم مارکس کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیں (اور مجھے اُمید ہے کہ اس کتاب میں ڈارون‘ میکڈوگل اور فرائڈ کے نظریات پر بحث کرتے ہوئے جو حقائق پیش کیے گئے ہیں اور جو حقائق زیر بحث موضوع کے سلسلہ میں پیش کیے جائیں گے وہ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں) تو اس کے فلسفہ کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔
مارکسی عقیدہ کے غلط نتائج
اگر ہم مارکس کے اس تصور کو صحیح مان لیں تو اس سے کئی بے ہودہ نتائج پیدا ہوتے ہیں:
اوّل : انسان کی تمام سرگرمیاں جو طلبِ جمال سے تعلق رکھتی ہیں (مثلاً آدرشوں کی جستجو‘ مذہب‘ اخلاق‘ سیاست‘ عقل‘ قانون‘ علم اور ہنر کی تمام قسمیں اور سائنس اور فلسفہ) جن پر انسان کو فخر ہے جن کی وجہ سے انسان حیوانات پر فضیلت رکھتا ہے اور جن پر انسان کی تہذیب ‘ شرافت اور عظمت کا دار و مدار ہے اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتیں اور اگر ہم اقتصادی حالات سے مطمئن ہو چکے ہوں تو پھر ان کا تتبع بے حقیقت اور بے معنی ہے۔
دوم : بعض وقت ایک انسان جسے بھوک لگتی ہے یا جسے کپڑا پہننے یا رہائشی مکان میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے روٹی یا کپڑے یا مکان کی ضرورت ہے لیکن بعض وقت وہ صاف طور پر نہیں کہتا کہ مجھے روٹی یا کپڑے یا مکان کی ضرورت ہے بلکہ وہ اپنی ان ضروریات کو بالکل بھول جاتا ہے اور اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اپنی اصلی اقتصادی ضروریات کے عوض میں انصاف اور نیکی اور صداقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ یا اخلاقی ‘مذہبی‘سیاسی اور روحانی نظریات کی جستجو شروع کر دیتا ہے۔ یا علم و ہنر کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تندرست ہوتا ہے۔ اس کا دماغ صحیح ہوتا ہے اُس نے کسی منشی چیز کا استعمال نہیں کیا ہوتا اور اُس کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں۔
سوم : جب ایک دولت مند شخص اپنی ساری اقتصادی ضروریات کو بفراغت پورا کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو کہ کئی نسلوں تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں تو اگر وہ نیکی صداقت اور انصاف کا نام لے یا کسی اخلاقی‘ روحانی‘ مذہبی یا سیاسی آدرش کی جستجو میں لگ جائے یا علم یا ہنر یا سائنس یا فلسفہ کا تتبع کرنے لگے تو سمجھ لوکہ اسے کوئی نہ کوئی اقتصادی ضرورت تنگ کر رہی ہے اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کون سی اقتصادی ضرورت پریشان کررہی ہے اور وہ کانوں پر ہاتھ دھر کر کہے کہ حاشا و کلا مجھے کوئی اقتصادی ضرورت پریشان نہیں کر رہی ۔ میرے پاس ہر چیز موجوجود ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے حالات سے بالکل بے خبر ہے۔
ناکام کوشش
نوٹ : اوپر کے دو نقاط کے سلسلہ میں اینگلز(Engles)نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے:
’’آدرش ایک ایسا عمل ہے جسے نام نہاد سوچنے والا بے شک جان بوجھ کر انجام دیتا ہے لیکن اس کی جان بوجھ غلط یا کاذب ہوتی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اصلی محرکات کیا ہیں۔ لہٰذا وہ ظاہری یا غلط محرکات کا تصور کرتاہے۔ چونکہ انسان کے سارے اعمال اس کے آدرش کی معرفت ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ غلطی سے سمجھتا ہے کہ وہ آدرش ہی پر مبنی ہیں‘‘۔
ظاہر ہے کہ یہاں اینگلز نے اپنے دعویٰ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیابلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے چند دعوؤں کا ایک سلسلہ پیش کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ایک شخص جو سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر ایک اخلاقی نظریہ کی پیروی کر رہا ہے اس کی جان بوجھ اور سوچ بچار غلط یا کاذب ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص یہ بات نہیں جان سکتا یا اُس کے پاس اس بات کے جاننے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے نظریہ کی جستجو ایک غلط یا کاذب احساس سے کر رہا ہے تو مارکس اور اینگلز کو کیونکر پتہ چل گیا کہ ہر شخص جو پورے احساس اور شعور کے ساتھ ایک آدرش کی جستجو کرتا ہے درحقیقت اس کا شعور یا احساس کاذب ہوتا ہے اور خود اُن کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس نظریہ کے لیے جسے مارکسزم کہا جاتا ہے اُن کا اپنا شعور یا احساس غلط اور کاذب نہیں۔
دعویٰ بلا دلیل
آخر ہمارے پاس یہ باور کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ جب ایک انسان سوچ سمجھ کر ایک آدرش کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے افعال کے اصل محرکات ‘جو ہمیشہ اقتصادی نوعیت کے ہوتے ہیں ‘اسے معلوم نہیں ہوتے اور وہ ان کی بجائے کاذب اور غلط محرکات کو جو ہمیشہ اخلاقی اور روحانی قسم کے ہوتے ہیں ذہن میں لاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ انسان کے اخلاقی اور روحانی محرکات جن کا وہ تصور کرتا ہے اُس کے اصل محرکات ہوتے ہیں اور اقتصادی محرکات جن کا تصور فقط مارکس اور اینگلز کے ذہن میں ہے درحقیقت موجود نہیں ہوتے یا ان محرکات کے ماتحت رہتے ہیں ۔بالخصوص جبکہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آدرشی یا روحانی اور اخلاقی مقاصد کے لیے اپنے اقتصادی مقاصد بلکہ اپنی زندگی تک کو قربان کر دیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اصلی محرکات تو ہمیشہ اقتصادی ہوں اور کاذب اور غلط محرکات ہمیشہ روحانی اور اخلاقی ہوں۔
اینگلز ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ اس نتیجہ پر کس طرح سے پہنچا ہے کہ انسان کا وہ فعل‘ جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے آدرش کا نتیجہ ہے‘ درحقیقت اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔اور ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ عملی اشتراکیوں کی حیثیت سے مارکس اور اینگلز کا ہر فعل درحقیقت اُن کے آدرش کا نتیجہ نہیں۔
مارکسیوں سے ایک سوال
ہم مارکس سے پوچھتے ہیں کہ اگر نظریات اور معتقدات اقتصادی حالات کی غلط‘ کاذب اور غیر شعوری اور مسخ شدہ فکری اشکال ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مرکز ہمیشہ حسن ‘ نیکی اور صداقت کے مجرد تصورات ہوتے ہیں۔ کیوں یہ نظریات اور معتقدات ہمیشہ ان ہی تصورات کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور ان ہی پر مشتمل ہوتے ہیں اور پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ جوں جوں ہمارا علم ترقی کرتا جاتا ہے وہ ان تصورات کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں اور تو اور جب ہم خود اقتصادی ناہمواریوں کا علاج کرنا چاہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم صرف جمہوریت‘ مساوات‘ اخوت‘ حریت‘ انصاف‘ اخلاق کی طرح کی ایسی اقدار کے لیے اپنا جوش ظاہر کرتے ہیں جو حسن‘ نیکی اور صداقت کے تصورات سے پیدا ہوتی ہیں۔ مارکسیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔
تاریخ کی گواہی
جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو صاف طور پر نظر آجاتا ہے کہ انسانی جماعتوں کی کوئی جدوجہد اور تاریخ کا کوئی انقلاب یا تغیر (خواہ اس کی نوعیت سیاسی ہو یا اخلاقی یا روحانی یا علمی یا مذہبی) ایسا نہیں جو ان اقدار کی طلب اور جستجو کا نتیجہ نہ ہو۔ فرانس کا انقلاب‘ روس کا انقلاب‘ امریکنوں کی جنگِ آزادی‘ جیک سٹرا(Jackstraw)کی قیادت میں انگلستان کے کسانوں کی جدوجہد‘ صلیبی جنگیں‘ تحریک اصلاح کلیسا (Reformation) اور تحریک احیائے علوم (Renaissance)تاریخ کے ان بے شمار واقعات میں سے چند ہیں جو اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں ۔ جب کبھی ہم سماج کے اندر کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہم دراصل ان ہی اقدار کو ایک ظاہر اور مرئی صورت میں لانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانا چاہتے ہیں ۔ خود مارکس نے بھی ان ہی اقدار کا نام لے لے کر اشتراکیت کی حمایت کی ہے اور وہ اپنی تحریر میں جابجا مساوات‘ انصاف اور آزادی پر زور دیتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہم حسن‘ نیکی اور صداقت کے لیے بھی ایک ایسی ہی بھوک محسوس کرتے ہیں جیسی روٹی کے لیے اور ان اقدار کی خواہشات درحقیقت انسان کی اصلی خواہشات ہیں جو اس کی خود شعوری کے ایک مستقل خاصہ کے طور پر اس کے اندر موجود ہیں اور اس کی باقی تمام خواہشات ان کے ماتحت ان کی خدمت گزار ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری یہ خواہشات اس وقت اظہار پاتی ہیں جب ہم اپنے اقتصادی‘ سیاسی ‘ علمی یا اجتماعی حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ کیونکر ثابت ہوتا ہے کہ یہ خواہشات مستقل اور اصلی نہیں بلکہ ماخوذ اور کاذب ہیں۔ آخر ان کے اظہار کے لیے کسی واسطہ کا ہونا تو ضروری ہے‘ محض خلاء میں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا بلکہ ان خواہشات کے مستقل اور اصلی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ فی الواقع ان حالات کو بدل کر اپنے مطابق کر لیتی ہیں۔
عقل و علم کا استخفاف
جو چیز مارکس کے اس موقف کو کہ طلب جمال کی تمام صورتیں یا اس کی اصطلاح میں ’’نظریاتی اشکال‘‘ اقتصادی حالات کا نتیجہ ہیں‘ حد درجہ مضحک بنا دیتی ہے ‘ یہ ہے کہ مارکس مجبور ہے کہ ان میں اخلاق اور مذہب ہی نہیں بلکہ عقل (Reason) اور علم اور فلسفہ اور سائنس بلکہ ریاضیات کو بھی شامل کرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر انسان کبھی یہ سمجھے کہ وہ ارد گرد کے اقتصادی حالات کے اثر سے آزاد ہو کر اپنی عقل کو کام میں لا رہا ہے یا اس کی عقل آزادانہ طور پر صداقت کی جستجو کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اگر عقل صداقت کو دریافت نہیں کر سکتی تو مارکسی اپنے فلسفہ کو صداقت کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں ۔ مارکسی کہتے ہیں کہ اُن کا فلسفہ عقل پر مبنی ہے لیکن اگر عقل اقتصادی حالات کے تابع ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور مارکس کا فلسفہ جس حد تک عقل پر مبنی ہے غلط ہے اگر مارکس کا فلسفہ بھی اقتصادی حالات کا ایک غیر شعوری اور بگڑا ہوا عکس ہے تو وہ صحیح کس طرح سے ہو سکتا ہے۔
قول و فعل کا تضاد
پھر اگر نظریات اقتصادی حالات کانتیجہ ہیں تو مارکسی دوسروں کے نظریات کی تردید اور اپنے نظریہ کا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا عقل سے کام لینے کی دعوت ہے اور یہ دعوت صرف اس مفروضہ کی بنا پر جائز ہو سکتی ہے کہ جب سرمایہ دار ممالک مارکسی نظریہ کے قائل ہو جائیں گے تو اشتراکی انقلاب رونما ہو گا۔ کیا اس سے مارکسیوں کے اس یقین کا ثبوت نہیں ملتا کہ نظریہ اقتصادی حالات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی حالات کو پیدا کرتا ہے۔
اپنے عقیدہ کی تغلیط
اور پھر اگر نظریات اقتصادی حالات سے پیدا ہوتے ہیں تو مارکسی لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنے کے لیے اتنی مصیبتیں کیوں اٹھاتے ہیں۔ مذہبی خیالات کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ واقعات ان کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ یہ خیالات ان اقتصادی حالات پر اثر انداز نہیں ہوسکتے جو مارکسی وجود میں لانا چاہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس مذہبی یا غیر مذہبی خیالات اقتصادی حالات سے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ مناسب اقتصادی حالات کب پیدا ہوتے ہیں۔ یا اگر ان اقتصادی حالات کو وجود میں لانے کی کوشش کریں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ وہ انہیں اپنی کسی سوچی ہوئی تجویز یا تدبیر کے ذریعہ سے وجود میں نہ لائیں کیونکہ وہ تدبیروں اور تجویزوں سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ خود تدبیروں اور تجویزوں کو پیدا کرتے ہیں۔
انسان کی الٹی تصویر
نظریات کے مبداء اور ماخذ کے متعلق مارکس کے تصورسے جو بے ہودہ نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دراصل مارکس نے انسان کو الٹاکر کے سر کے بل کھڑا کر دیا ہے انسان کی فطرت کا صحیح نقشہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظریات اور معتقدات کے مطابق اپنے تمام حالات کو بدلتا ہے ۔ لیکن مارکس کا خیال بالکل برعکس ہے۔
قابلِ غور بات
یہ بات قابل غور ہے کہ نظریات کے منبع اور ماخذ کے متعلق کارل مارکس کی غلط فہمی کوئی انوکھی بات نہیں۔ اس غلط فہمی میں مارکس‘ میکڈوگل‘ فرائڈ اور ایڈلر کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ نظریات اور معتقدات کے لیے انسان کی فطرت میں کوئی مستقل خواہش یا جذبہ موجود نہیں بلکہ ان کا باعث یا تو کوئی ایک حیوانی جبلت ہوتی ہے اور یا تمام حیوانی جبلتوں کا مجموعہ تاہم ان کے اصل منبع کے متعلق ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں۔
میکڈوگل کی تصحیح
میکڈوگل کے نظریہ میں جس قدر غلطیاں اور الجھنیں موجود ہیں اُن کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدرشوں کو تمام حیوانی جبلتوں کے مجموعہ کے تابع سمجھتا ہے۔ لہٰذا وہ معقول طور پر نہیں بتا سکتا کہ فطرت انسانی کے اندر عزم یا ارادہ جو حصول آدرش کی ایک اندرونی کوشش کا نام ہے کہاں سے آتا ہے اور اُس کے خیال کی تردید کے لیے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نظریات کی محبت انسان کی فطرت کا ایک مستقل خاصہ ہے اور اس کی زندگی کا واحد محرک عمل ہے اور جبلتوں سے اس کا کوئی تعلق سوائے اس کے نہیں کہ جبلتیں اس کے ماتحت اس کی خدمت گزار بن کر رہتی ہیں۔ اس مفروضہ کو درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں ان حقائق سے بھی مدد ملی تھی جو زندگی یا شعور کی حقیقت کے بارہ میں نظریۂ ڈارون کی تردید کے لیے پیش کیے گئے تھے پھر ہم نے دیکھا تھاکہ یہ مفروضہ میکڈوگل کی تمام غلطیوں اور اُلجھنوں کو دُور کر کے اس کے نظریۂ جبلت کو صحیح کر دیتا ہے اور اس بات سے اس کی اپنی صحت کی بھی ایک دلیل پیدا ہوتی ہے۔
فرائڈ کی تصحیح
اس طرح سے فرائڈ کے نظریہ میں جس قدر غلطیاں اور پریشان خیالیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریات کو آبائی الجھاؤ کی صورت میں جبلتِ جنس کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا وہ معقول طور پر نہیں بتا سکا کہ آبائی الجھاؤ نظریات کی صورت کیونکر اختیار کر لیتا ہے اور فرائڈ کے نظریہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں پھر یہی ثابت کرنا پڑا تھا کہ نظریات کی محبت انسان کی فطرت کا ایک مستقل خاصہ ہے اور اس کی زندگی کا واحد محرک عمل ہے جس کا نام نہا دآبائی الجھاؤ سے سوائے اس کے اور کوئی تعلق نہیں کہ وہ دراصل والدین کی غیر جنسی محبت کی صورت میں اس کی پیداوار ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مفروضہ فرائڈ کے نظریۂ لاشعور کو بھی اغلاط سے پاک کر کے معقول اور مدلل بنا دیتا ہے اور اس طرح سے نہ صرف اپنی صحت اور درستی کی ایک اور دلیل مہیا کرتا ہے بلکہ میکڈوگل کے نظریہ کی تردید کو بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے۔
ایڈلر کی تصحیح
اسی طرح سے ایڈلر(Adler)کے نظریہ کے اندر بھی جس قدر غلطیاں اور الجھنیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریات کو بچپن کے احساسِ کہتری کی صورت میں جبلت تفوق کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اس تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ نظریات کی محبت انسان کی فطرت کا ایک مستقل خاصہ ہے جو کسی احساسِ کہتری یا جبلت تفوق کا نتیجہ نہیں بلکہ کہتری کا احساس اور تفوق اور استیلاء کی خواہشات خود اس کا نتیجہ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مفروضہ ایڈلر کی مشکلات کا ازالہ بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح میکڈوگل اور فرائڈ کی مشکلات کا اور نہ صرف ایڈلر کے نظریہ کو اغلاط سے پاک کر کے معقول اور مدلل بنا دیتا ہے بلکہ اپنی صحت کی ایک اور شہادت پیداکر کے میکڈوگل اور فرائڈ کے نظریات کی تردیدکو بھی اور قوت اور سہارا دیتا ہے۔
مارکس کی تصحیح
بالکل اسی طرح سے کارل مارکس کے نظریہ کے اندر جس قدر غلطیاں موجود ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ وہ نظریات کو اقتصادی حالات کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اس کے نظریہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں پھر یہی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ نظریات کی محبت انسان کی فطرت کا ایک مستقل خاصہ ہے اور اس کی زندگی کا واحد محرک عمل ہے۔ لہٰذا وہ تمام حقائق جو ڈارون‘ میکڈوگل‘ فرائڈ اور ایڈلر کے نظریات کے غلط تصورات کی تردید اور صحیح تصورات کی تائید میں ہماری طرف سے یا ان حکماء کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں‘ کارل مارکس کے نظریہ کی تردید کرتے ہیں اور اس کی تردید کے لیے کفایت کرتے ہیں۔
موضوع بحث
تاہم کارل مارکس کے نظریہ کی خامیوں کو پوری طرح سے آشکار کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اقتصادی ضروریات اور حالات کا نظریات اور معتقدات کے ساتھ درحقیقت کیا تعلق ہے اور کتاب کے اس باب میں یہی موضوع زیربحث رہے گا۔
بہکنے کے اسباب
بعض لوگ ‘جو غور اور باریک بینی سے حقائق کا مطالعہ کرنے کے عادی نہیں مارکس کے اس خیال سے کہ نظریات اقتصادی ضروریات اور حالات کا نتیجہ ہیں‘ بآسانی بہک جاتے ہیں اور اس کی چند وجوہات ہیں:
اوّل : ہماری بنیادی معاشی ضروریات مثلاً خوراک‘ کپڑا اور مکان بعض جبلتی خواہشات پر مبنی ہیں جن کے اندر ایک ایسا حیاتیاتی دباؤ ہے جو فرد اور نوع کی زندگی میں شروع ہی سے موجود ہوتا ہے اور جسے ہر شخص محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے اس کے برعکس آدرشوں کا نفسیاتی دباؤ غیر شعوری ہوتا ہے اور اگرچہ لوگ ہر وقت اس دباؤ کی طاقت اور قوت کے ماتحت کام کر تے ہیں۔ لیکن اس کی طاقت اور قوت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہر دباؤ فرد یا نوع کی زندگی میں صرف اس وقت واضح طور پر سمجھ میں آنے لگتا ہے جب نظریات ذرا بلند ہوجاتے ہیں اور بقائے حیات کی جبلتی خواہشات سے الگ نظر آنے لگتے ہیں۔
دوم : چونکہ آدرش ہی کی جدوجہد کی خاطر سب سے پہلے زندہ رہنا ضروری ہے اس لیے لوگ اپنے آدرش کی اصلی ضروریات سے پہلے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔
سوم : انسان کی بنیادی معاشی اور جبلتی ضروریات کی تکمیل کے اندر قدرت نے ایک لذت رکھی ہے جس کی غرض یہ ہے کہ انسان بقائے حیات کے فریضہ سے غافل نہ ہونے پائے۔بعض انسان اس لذت کو ہی اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں اُن کے لاشعوری جذبۂ حسن کی قوت ان خواہشات کے راستہ سے نکاس پانے لگتی ہے اور ان خواہشات سے الگ ان کا کوئی نظریہ باقی نہیں رہتا۔
چہارم : جب ہمارا آدرش بہت بلند ہو اور معاشی ضروریات سے الگ نظر آ رہا ہو تو اس وقت بھی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے آدرش کی خاطر اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کو نظرانداز نہ کریں اور ان کی اہمیت کم نہ ہونے دیں۔
پنجم : جب ایک معاشرہ کے اندر اقتصادی حالات خراب ہوں ‘ مثلاً دولت کی تقسیم غیر مساوی ہو اور بعض لوگوں کے ساتھ ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہو تو اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ ایک غلط آدرش معاشرہ پر اپنی حکومت قائم کر چکا ہوتا ہے اور معاشرہ کی خرابیاں جب آشکار ہوتی ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرہ کا نظریہ ‘جو ان کاباعث ہے‘ غلط ہے اور اوصافِ حسن سے عاری ہے۔لہٰذا ہم اس نظریہ کو بدلنے کا اقدام کرتے ہیں جسے سیاسی یا اجتماعی انقلاب کہا جاتا ہے۔ نظریہ کے بدلنے کے ساتھ اقتصادی حالات بدل کر درست ہو جاتے ہیں کیونکہ نیا آدرش جسے ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کے ماتحت انقلاب پیدا کرتے ہیں اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نقائص نہیں ہوتے‘ جو پہلے آدرش میں تھے اور جن کی وجہ سے معاشرہ کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی تھیں۔
نظرِ غائر کا مشاہدہ
ان حقائق کو سطحی نظر سے دیکھنے والا انسان فوراً اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نظریات ہماری اقتصادی ضروریات سے پیدا ہوتے ہیں اور ان ضروریات کے مقابلہ میں غیر اہم اور غیر ضروری ہیں۔ اور معاشی ضروریات انسان کی امدادی ضروریات نہیں بلکہ بنیادی ضروریات ہیں لیکن اگر ان حقائق کو بغور دیکھا جائے تو کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ہم اپنی معاشی ضروریات کو ہمیشہ اپنے نظریہ کی ضروریات کے ماتحت مطمئن کرتے ہیں اور اقتصادی حالات ہمیشہ نظریات سے پیدا ہوتے ہیں اور نظریات کے ماتحت رہ کر ان کی خدمت اور اعانت کرتے ہیں اور ان کے بدلنے کے بغیر نہیں بدلتے۔ اور جب ہم انہیں بدلتے ہیں تو ہمیشہ اپنے جذبۂ حسن کے تقاضوں سے مجبور ہو کر بدلتے ہیں ہماری اصلی اور بنیادی ضرورت جذبۂ حسن کی تشفی ہے جس کا نتیجہ نظریات کی محبت ہے۔
انسان بھوک پر غالب ہے
اس میں شک نہیں کہ قدرت نے بھوک کی خواہش کے اندر ایک زبردست حیاتیاتی دباؤ رکھا ہے ‘جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسے مطمئن کریں‘ لیکن یہ قدرت کی ایک امداد اور ایک مہربانی ہے جسے ہم کبھی قبول کر لیتے ہیں اور کبھی رد کر دیتے ہیں ۔ ضرورت کے وقت ہم اس دباؤ پر غالب آ سکتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ بے شک ہم بالعموم بھوک کی طرف سب سے پہلے توجہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آدرش کا تقاضا بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آدرش بالعموم چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہ کر اس کی جستجو کرتے رہیں۔ لیکن جب آدرش کا تقاضا اس کے برعکس ہو یعنی وہ مطالبہ کر رہا ہو کہ بھوک سے بلکہ زندگی سے قطع نظر کر دو تو ہم بھوک کی مجبور کرنے والی قوت کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کرتے اور بھوک سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
مثالیں
آئرستان کے قائد ڈی ولیرا (De Valera) اور ہند کے قائد مہاتما گاندھی کا دو دو ماہ تک خوراک سے انکار کر دینا اس کی مثالیں ہیں۔ایک سپاہی جو وطن کی محبت سے سرشار ہو‘ میدانِ جنگ میں بھوک اور پیاس کی خواہشات اور خود زندگی کی خواہش سے بے نیازہو کر لڑتا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم میں لاکھوں روسیوں نے خود اپنی معاشی ضروریات اور اپنی زندگی سے بے پرواہ ہو کر اپنے نظریہ کی خاطر سینوں میں گولیاں کھائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری فطرت کی اصلی اور بنیادی ضرورت نظریہ ہے نہ کہ خوراک۔ خوراک کا مقصد آدرش کے حصول کی خاطر زندگی کا قیام ہے۔ جب آدرش کے حصول کے لیے زندگی قربان کرنا ضروری ہو جائے تو ہم زندگی کی پرواہ نہیںکرتے۔
آدرش کے ماتحت مقاصد
ایک آدرش ہمارے تمام افعال کا آخری مقصد ہوتا ہے لیکن اس آخری مقصد کے ماتحت اُس کے حصول کے ذرائع کے طور پر بعض اور قریب تر مقاصد بھی آتے ہیںجن میں سے ہر ایک کا حصول آخری مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ان فوری مقاصد میں سے ہر ایک مقصد خود منتہائے مقصود نہیں ہوتا بلکہ منتہائے مقصود کے ماتحت ایک امدادی وسیلہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آخری مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کی اہمیت اتنی ہی ہو جاتی ہے جتنی کہ آخری مقصد کی۔ لہٰذا ہم سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ گویا ہم نے اس امدادی اور فوری مقصد کی خاطر اپنے آدرش ہی کو چھوڑ دیا ہے یا یہ مقصد ہمارے نزدیک آدرش سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور غلطی کیا ہو گی۔
معاشی ضروریات اور آدرش
یہی حال ہماری بنیادی معاشی ضروریات کا ہے۔ ان ضروریات کی ساری اہمیت یہ ہے کہ اُن کے بغیر ہم اپنے آدرش کی جستجو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے جب آدرش کے ماتحت مقاصد کی حیثیت سے اُن کا حصول خطرہ میں پڑ جاتا ہے تو ہم اُن کو آدرش کے برابر اہمیت دینے لگتے ہیں۔ لیکن جب اُن کی طرف توجہ دینا ہمارے آدرش کے لیے بجائے فائدہ کے نقصان کا موجب ہوتا ہے تو ہماری نگاہوں میں اُن کی اہمیت صفر کے برابر رہ جاتی ہے اس صورت میں ہم انہیں نظر انداز کر کے اپنے آدرش کے مطالبہ کو پورا کرتے ہیں۔
جبلتوں کے جبر کا فائدہ
ہماری بنیادی معاشی ضروریات آدرش کے حصول کے لیے ہمارے فوری اور قریبی مقاصد یا ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا یہ قریبی یا فوری مقصد یا ذریعہ اپنے اندر ہمیں مجبور کرنے کا سامان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حیثیت ایک ذریعہ یا وسیلہ سے زیادہ نہیں۔ جبلتی خواہشات کو انسان ارتقاء کے دوران میں حیوانات سے وراثت میں لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر حیوان قدرت کی طرف سے ان خواہشات کی تکمیل پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو اپنی غیر شعوری سی زندگی میں جو قدرت نے اسے دی تھی وہ ان کی تکمیل کی طرف سے غافل ہو جاتا اور جب وہ خود زندہ نہ رہتا تو اس کی نسل کہاں سے آتی اور روئے زمین پر انسان کا ظہور کس طرح سے ہوتا۔
عملِ ارتقاء میں جب یہ خواہشات انسان تک پہنچتی ہیں تو انسان کو بھی (جب آدرش کا تقاضا ‘ زندگی کا قیام اور جبلتی خواہشات کی تائید ہو) ان کا دباؤ یا جبر قیامِ حیات کے فریضہ سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ ان خواہشات کے اندرنی حیاتیاتی دباؤ سے ایک اور فائدہ جو انسان کو پہنچتا ہے یہ ہے کہ جب آدرش کا تقاضا جبلتی خواہشات کی مخالفت ہو تو یہ دباؤ انسان کو غیر معمولی جدوجہد پر مجبور کرتا ہے جس سے اس کی خود شعوری کی محبت ترقی کرتی ہے۔
بھوک کی جبلت اور آدرش
جو شخص اپنی بھوک کی جبلت کو مطمئن کرتا ہے وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے آدرش کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے لیے ہمارے جسم کے اندر کوئی حیاتیاتی دباؤ موجود نہ ہوتا اور ہم کو معلوم ہوتا جیسا کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ خوراک بقائے حیات کے لیے ضروری ہے تو ہم اس صورت میں بھی کھانا کھانے کا التزام کرتے۔ بھوک کے فطرتی جبر یا دباؤ کی وجہ سے ہمیں ایسا معلو م ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے ہمارا مقصد فقط بھوک کا ازالہ ہے اور ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم فقط اپنے نظریۂ حیات کی خاطر زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا کھانا اور زندہ رہنا فقط کھانے اور زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ آدرش کے حصول کے لیے ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب نظریہ کا مطالبہ اس کے برعکس ہو تو ہم کھانے اور زندہ رہنے سے دستکش ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا نظریہ خواہ وہ بلند ہو یا پست‘ اچھا ہو یا برا ہم سے مطالبہ کرے تو ہم اپنی تمام معاشی ضروریات اور جبلتی مجبوریوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی زندگی اور اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
ایک غلط نتیجہ
اس میں شک نہیں کہ نوع کی زندگی میں بھوک کی جبلت اس وقت سے چلی آتی ہے جب پہلا جاندار عدم سے وجود میں آیا تھا اور نظریات کی محبت کا جذبہ کروڑہا سال کے بعد انسان میں نمودار ہوا ہے اور یہی نوع کی تاریخ فرد میں دہرائی جاتی ہے ۔ فرد کی زندگی میں بھی بھوک کی جبلت ابتدا ہی سے موجود ہوتی ہے اور نظریات کی محبت کا جذبہ عمر کے ایک خاص حصہ میں‘ جب فرد کا علم کافی حد تک ترقی کرجاتا ہے اور نظریات بلند ہوجاتے ہیں ‘ بین طور پر نظر آنے لگتا ہے ۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ نظریات کی محبت ہماری بنیادی معاشی ضروریات کا نتیجہ ہے یا ہماری بنیادی معاشی ضروریات نظریات کی محبت کا باعث ہیں۔
خادمانہ حیثیت
یہ امر کہ بھوک کی جبلت فرد اور نوع کی تاریخ میں نظریات کی محبت سے پہلے موجود ہوتی ہے‘ اس بات کی دلیل ہے کہ بھوک کی جبلت ادنیٰ اور خادمانہ حیثیت رکھتی ہے اور نظریات کی محبت اُس سے بلند تر اور اعلیٰ تر ایک خواہش ہے ۔ ارتقا ہمیشہ بہتر اور بلند تر مقاصد کی طرف حرکت کرتا ہے ورنہ وہ ارتقا نہ ہو بلکہ تنزل ہو۔
ایک مثال
کائنات کا ارتقا ایسا ہی ہے ‘جیسے ایک درخت کی نشوونما کہ جوں جوں ہم آگے جاتے ہیں اس کے نتائج زیادہ گراں قدر ہوتے جاتے ہیں۔یہاں تک کہ اگر ضرورت ہو تو ان کی حفاظت کے لیے ارتقا کے گزشتہ حاصلات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پھول‘ پھل اور بیج درخت کی نشوونما کے آخری مرحلہ میں پیدا ہوتے ہیں تاہم وہ درخت کی نشوونما کا حاصل اور نچوڑ ہیں اور درخت کی غور پرداخت کی ساری زحمتیں ان ہی کی خاطر گوارا کی جاتی ہیں۔
حکمران محرکِ عمل
مادی مرحلہ ارتقا میں ارتقا کا نتیجہ مادی قوانین ہیں۔ حیوانی مرحلہ میں ارتقا کا نتیجہ جبلتیں ہیں اور انسانی مرحلہ میں اس کا نتیجہ نظریات کی محبت ہے۔ جس طرح سے جبلتیں مادی قوانین پر حکمران ہیں اور ان کی مخالفت کر سکتی ہیں وہ محرک عمل جو بعد میں پیدا ہوتا ہے اس محرک عمل پر ‘جو اس سے پہلے ظہور میںآتا ہے ‘ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ محض ایک مفروضہ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتارہتا ہے۔ حیوان جبلتوں کی تشفی کے لیے قوانین مادہ کے خلاف نبرد آزما ہے اور انسان نظریات کی محبت کی تشفی کی خاطر جبلتوں کے ساتھ برسرپیکار ہے۔
جبلتی تقاضوں سے انسان کی بے پرواہی
اس میں بھی شک نہیں کہ ہم بالعموم سب سے پہلے جبلتوں کی تشفی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بھوک کی حالت میں ہم خوراک چاہتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ بھریں اور فلسفہ اور علم اور ہنر کی طرف راغب نہیں ہوتے ۔ نہ نماز اور ذکر اور فکر کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے نفسیاتِ انسانی کا ایک عام قائدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم روٹی کو اپنی نظریاتی سرگرمیوں پر ترجیح دیتے ہیں یا نظریاتی سرگرمیاں اقتصادی ضروریات کے ماتحت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں جب ہم بھوک اور اس قسم کی دوسری مجبور کرنے والی جسمانی ضروریات کی طرف سب سے پہلے متوجہ نہیں ہوتے اور ان کو چھوڑ کر بلکہ اُن کی مخالفت کر کے نظریات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اُن تقاضوں کو اپنی تمام ضروریات سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم اپنی جسمانی ضروریات کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتے ہیں تو ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر محض اپنے نظریات کی خاطر ایسا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان ضروریات کو پورا کر کے اپنی زندگی برقرار رکھیں اور نظریات کی جستجو کرتے رہیں۔
نظریات اور جبلتی ضروریات کا صحیح تعلق
اکثر اوقات ہم نظریات کی قوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پوری طرح سے اس کا اندازہ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے نظریات اتنے بلند ہوں کہ وہ جسمانی ضروریات سے الگ نظر آ رہے ہوں تو پھر بھی بالعموم ان کی محبت پوری طرح سے ترقی یافتہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم نظریات اور جسمانی ضروریات کا تعلق ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہیں اور اس کی بنا پر فطرت انسانی کا ایک عام قاعدہ وضع کرنا چاہیں تو غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں ان نادر الوقوع مثالوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے جن میں نظریات کی محبت ترقی کر کے انتہا درجہ کی قوت حاصل کر چکی ہوتی ہے مثلاً ایک شخص جو دولت مند ہونے اور عمدہ اور لذیذ غذاؤں کی استطاعت رکھنے کے باوجود زہد اور ریاضت کے خیال سے سادہ اور کم غذا کھاتا ہے یا متواتر روزے رکھتا ہے۔ یا دن میں ایک دفعہ کھاتا ہے یا ایک بہادر سپاہی جو اپنے مذہب ‘اپنی قوم یا اپنے وطن عزیز کی خاطر برضا و رغبت اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے یا ایک شہزادہ جو عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر ایک رات شاہی محل سے نکل جاتا ہے اور برسوں صرف صداقت کی جستجو کے لیے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ یا ایک پیغمبر جو اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر ایک بت پرست جنگجو اور جاہل قوم کو ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتا ہے اور دولت کے کسی لالچ سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ نظریات کے مارکسی تصور کے مطابق ان مثالوں کی کوئی معقول تشریح ممکن نہیں۔
محب ِوطن سپاہی کی نفسیات
شاید ایک مارکسی کہے گا کہ جب ایک بہادر سپاہی اپنے وطن کے لیے جان قربان کرتا ہے تو اس کا نظریۂ حب الوطنی درحقیقت اقتصادی حالات کی پیداوار ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم اس کی قربانیوں کی وجہ سے اقتصادی فائدہ حاصل کرے گی۔
غلط استدلال
لیکن یہ استدلال سراسر مغالطہ آمیز ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا نظریہ جو اسے موت سے ہم آغوش ہونے کی دعوت دیتا ہے اس کے اپنے اقتصادی فائدہ کے خیال سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف اپنے تمام اقتصادی فوائد کو قربان کرتا ہے بلکہ اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے جس کی حفاظت کے لیے اسے اقتصادی فوائد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی اصل غرض اگر یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنے آپ کے لیے بہتر غذا کا اہتمام کرے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر کار اس نے اپنی زندگی کو اس لیے گنوا دیا کہ دوسروں کے لیے بہتر غذا کا اہتمام ہو جائے۔
قیمتی مقصد
مر کر دوسروں کو بہتر غذا مہیا کرنے کی بجائے یہ بات اس کے اصلی مقصد کے زیادہ مطابق تھی کہ وہ زندہ رہتا اور کمتر درجہ یا کمتر مقدار کی خوراک کھانے پر قناعت کرتا ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس مقصد کی خواہش اسے ترکِ زندگی پر آمادہ کرتی ہے وہ اس کے نزدیک اُس کے یا دوسروں کے زندہ رہنے اور اپنی اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے امکان سے بہت زیادہ قیمتی ہے اگر اس کی موت کے بعد اس کی قوم کو کوئی اقتصادی فائدہ حاصل ہو جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا فعل کسی اقتصادی فائدہ کی امید پر مبنی تھا کیونکہ وہ خود ہر قسم کے اقتصادی فوائد کو قربان کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے بھی اس کا ہر فعل اس کی اپنی ہی خواہشات کا نتیجہ ہو۔ ضروری ہے کہ افراد جو کام مل کر کریں وہ اُن میں سے ہر ایک کی ذاتی انفرادی خواہش کا نتیجہ ہو۔ جماعت بہرحال افراد کا ایک مجموعہ ہے اور جماعت کا فعل افراد کے افعال کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جماعت کے اندر رہ کر ‘جماعت کے ساتھ مل کر اور جماعت کے مجموعی فائدہ کی خاطر کوئی کام کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا باعث ایک ایسی خواہش ہو ‘جو سب سے پہلے فقط اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہو اور جس کافائدہ سب سے پہلے اُس کی ذات کو پہنچتا ہو ‘ورنہ وہ کام اس سے ہرگز صادر نہیں ہو گا۔
روحانی آسودگی
ظاہر ہے کہ محب وطن سپاہی اپنی جان کسی مادی یا اقتصادی فائدہ کے لیے نہیں بلکہ کسی نظریہ(Ideal)یا تصور (Idea)کے لیے یعنی کسی روحانی یا نفسیاتی فائدہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اس کی قربانیوں کا باعث وہی آدرش کی محبت ہے جو اُس کے جذبۂ حسن سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس کے تمام افعال کا ماخذ اور منبع ہے۔ فائدہ جو اس کی ذات کو حاصل ہوتا ہے وہ فقط ایک باطنی تسلی یا آسودگی(Satisfaction) ہے کہ اس نے اپنے نظریہ کی اطاعت کی ہے اور اس کے مطالبہ یا تقاضا کو پورا کر دیا ہے۔ یہ تسلی یا آسودگی ایک خاص نوعیت رکھتی ہے جو اقتصادی فوائد سے حاصل ہونے والی تسلی یا آسودگی سے بہت مختلف ہے۔ اس تسلی کے بغیر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا‘ نہایت ہی مضطرب اور پریشان ہوتا اور ایک دائمی ذہنی آزار میں گرفتار ہو جاتا۔
اتفاقی فائدہ
اگر اس کی قوم کو کوئی اقتصادی فائدہ حاصل ہو جائے تو اس کی وجہ اس کے نظریہ کی نوعیت ہو گی۔ لیکن وہ خود اپنے نظریہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ اقتصادی فوائد کا منبع ہے بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ حسین تصور ہے۔ بہت سے نظریات ایسے بھی ہیں کہ جب فرد اُن کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس کے نتیجہ کے طور پر دوسروں کو کسی اقتصادی فائدہ کی توقع نہیںہوسکتی۔
جبلتی اور نظریاتی خواہشات کا عارضی انطباق
میکڈوگل کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ فرد کی زندگی اور نوع کی تاریخ کے ابتدائی مراحل میں جب ہمارے علم اور ہماری خود شناسی کا معیار بہت پست ہوتا ہے تو ہمار جذبۂ حسن جبلتی خواہشات کے راستہ سے اظہار پانے لگتا ہے۔ کیونکہ ان خواہشات کی لذت سے بہتر کوئی تصور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں ہمارا نظریہ ہماری جبلتی خواہشات کے ساتھ کلیتاً منطبق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اس کو ان خواہشات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اس حقیقت کی وجہ سے ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اقتصادی ضروریات کے علاوہ ہماری کوئی اور ضروریات نہیں اور اگر کوئی اور ضروریات ہیں تو وہ بعد میں ان ہی ضروریات سے پیدا ہوتی ہیں حالانکہ نظریات کی ظاہری عدم موجودگی صرف فرد اور نوع کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ممکن ہے اور ان مراحل میں بھی جبلتی خواہشات کی غیر معمولی قوت اور اہمیت ہی ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہماری کوئی اور خواہشات ایسی ضرور ہیں جو اپنے آپ کو غلط طور پر جبلتی خواہشات سے منطبق کر کے اُن کو غیر معمولی قوت دے رہی ہیں لیکن جب ہمارا علم ترقی کرتا ہے اور ہمارا نظریہ بلند ہو کر جبلتی خواہشات سے ممیز ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اور فوقیت ظاہر ہوجاتی ہے تو ہمیں اس حقیقت کا ایک واضح ثبوت میسر آ جاتا ہے کہ نظریات اپنا علیحدہ اور مستقل وجود رکھتے ہیں اور ان کا ارتقا خاص قوانین کا پابند ہے۔
انسان کی شدید ترین خواہش
ہماری خود شعوری چاہتی ہے کہ حسن اور صداقت کو جہاں تک ممکن ہو مکمل طور پر زندگی کے خارجی حالات کے اندر وجود میں لائے۔ اس خواہش کا سبب خود شعوری کا وہی لاشعوری جذبۂ حسن ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا گیا ہے۔ خود شعوری اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے جب وہ حسن کی ایک نئی جھلک دیکھتی ہے یا حسن کے کسی ایسے وصف کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھا تو وہ اس خواہش کو روٹی بلکہ زندگی کی خواہش سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ خود شعوری کے تقاضائے حسن کو ایک لمحہ کے لیے بھی رد کر سکیں ۔ گو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس تقاضا کی ترجمانی غلط طور پر کرتے ہیں اور اس کے ایک جزو کو اس کا کل سمجھ لیتے ہیں ۔ کارل مارکس خود ایک ایسے فلسفہ کی تدوین کرکے جو انصاف اور آزادی کی خواہش سے لبریز ہے نادانستہ طور پر اسی جذبۂ حسن کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے فلسفہ کے اندر عدل‘ مساوات ‘ حریت ایسے اخلاقی اقدار کا ذکر‘ جن کی حمایت مذہب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے‘ بار بار آتا ہے۔
انصاف کی محبت ایک فطرتی جذبہ ہے
انصاف کی خواہش خود شعوری کے جذبۂ حسن کا ایک پہلو ہے۔ انصاف کی خواہش صرف اشتراکیوں کا حصہ نہیں بلکہ یہ خواہش ہر فردِ بشر کے دل میں موجود ہوتی ہے خواہ وہ معاشی طبقات میں سے کسی طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ انصاف ہم سے فلاں عمل کا تقاضا کرتا ہے تو ہم اس عمل کی زبردست خواہش محسوس کرتے ہیں اور جونہی کہ ہم میں بے انصافی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے ‘ ہم بے انصافی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ تر اس لیے نہیں کہ وہ معاشی ناہمواری کا موجب ہو گی بلکہ اس لیے کہ انصاف سے محبت کرنا اور بے انصافی سے نفرت کرنا ہماری فطرت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بے انصافی سے ہم نہ صرف اس وقت نفرت کرتے ہیں جب اس کا نقصان ہم کو پہنچ رہا ہو بلکہ اس وقت بھی نفرت کرتے ہیں جب اس سے دوسرے لوگ متأثر ہو رہے ہوں اور ہم صرف اس بے انصافی سے نفرت نہیں کرتے جس کا تعلق دولت کی تقسیم سے ہو بلکہ اس بے انصافی سے بھی نفرت کرتے ہیں جو ہماری یادوسروں کی شرافت‘ قابلیت یا سیرت کے بارہ میں رائے قائم کرتے ہوئے روارکھی جائے اور ظاہر ہے کہ شرافت اور سیرت روپیہ کمانے کے ذرائع نہیں بلکہ ہم ان کی حفاظت کے لیے اکثر دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نہ صرف دوسروں کی بے انصافی کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ جب اپنی بے انصافی پر متنبہ ہوجائیں تواس کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بے انصافی کی نفرت اورانصاف کی محبت کا جذبہ اقتصادی حالات کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری فطرت کا ایک مستقل تقاضا ہے جو ہر حالت میں اپنا عمل کرتا ہے ۔اس تقاضا کا ماخذ خود شعوری کا جذبۂ حسن ہے۔
تغیر نظریات کا مارکسی تصور
مارکس کہتا ہے کہ ہم اپنی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو سامان یا اشیاء پیدا کرتے ہیں اُن کی پیدائش کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ طریق پیدائش کی ہر حالت‘ خاص قسم کے مذہبی‘ اخلاقی‘ سیاسی یا فلسفیانہ نظریات اور معتقدات پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر نظریات اور معتقدات کی اپنی کوئی جداگانہ ہستی نہیں تو پھر بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ طریق پیدائش کی حالتیں انہیں کیوں پیدا کرتی ہیں۔
کارل مارکس کے خیال میں ایک سیاسی یا اجتماعی انقلاب کا باعث یہ ہوتا ہے کہ جب نئے ذرائع پیدائش ظہور میں آتے ہیں تو اُن کے اثر سے پیدائش کے نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور ایک نیا طریق پیدائش یا نیا اقتصادی نظام وجود میں آتا ہے اور جب کوئی اقتصادی نظام یا طریق پیدائش بدلتا ہے تو نظریات اور معتقدات بھی اس کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔
غلط توجیہہ
یہاں مارکس نے حقیقت حال کو نہایت ہی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ نظریات اقتصادی نظام کے بدلنے کے بعد یا اس کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتے بلکہ پہلے بدلتے ہیں اور ان کے بدلنے کی وجہ سے ایک نیا اقتصادی نظام وجود میں آتا ہے۔ جب آدرش بدل جائے تو چونکہ آدرش انسان کے تمام اعمال کا سرچشمہ ہے ضروری ہے کہ نہ صرف انسان کے اقتصادی حالات بلکہ اس کی زندگی کے تمام حالات بدل جائیں۔
صحیح توجیہہ
لیکن آخر آدرش کیوں بدلتا ہے۔ مارکس نے جان بوجھ کر اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ آدرش کے بدلنے کی صرف ایک ہی توجیہہ ایسی ہے جو تمام حقائق کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتی ہے۔ اور لہٰذا پوری طرح سے واضح‘ معقول اور قابل قبول ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدرش کے تغیر کا باعث انسان کی خواہش حسن و کمال ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے آدرش کو ہر قسم کے نقائص سے پاک کر کے اسے کامل سے کامل تر بناتا جائے ۔ جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آدرش حسن و کمال کی بعض صفات سے عاری ہے یعنی اس کی وجہ سے معاشرہ کے حالات غیر تسلی بخش ہو گئے ہیں۔ مثلاً ان کی وجہ سے ظلم‘ بے انصافی یا غلامی کا دوردورہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے آدرش کو بدلنے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں حسن‘ نیکی اور صداقت کی نقیض ہیں اور اُس کی فطرت اُن سے نفرت کرتی ہے۔ یہ امر کہ انسان حسن‘ نیکی اور صداقت کی خواہش کو اپنی زندگی کے حالات کو بدل کر یا سدھار کر پورا کرتا ہے ہرگز اس بات کے منافی نہیں کہ یہ خواہش انسان کی فطرت میں اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو اور اقتصادی حالات کی ایک اتفاقی پیداوار نہ ہو۔
حقائق سے چشم پوشی
مارکس نے سیاسی اور اجتماعی انقلابات کی جوتشریح کی ہے وہ فطرتِ انسانی کے حقائق کو نظر انداز کرتی ہے۔ دراصل تمام سیاسی اور اجتماعی انقلابات خود شعوری کے جذبۂ حسن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس جذبہ کی وجہ سے ہم حق و باطل میں اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ اور خوب و ناخوب میں امتیاز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان سیاسی یا اقتصادی حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں‘ جنہیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے ‘اگر یہ نہ ہو تو ہم ہر قسم کے اقتصادی اور سیاسی حالات کے ساتھ مطمئن رہیں بلکہ ہمیں سیاست اور اقتصادیات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور ہم حیوانات کی طرح (محض اپنی جبلتوں کے جبر کے ماتحت) زندگی بسر کریں۔
نئے آدرش کا ظہور
جب ہم ایک غلط نظریہ کے ماتحت (جو ہماری فطرت کے لاشعوری جذبۂ حسن سے مطابقت نہیں رکھتا اور بالآخر اسے مطمئن نہیں کر سکتا) محبت کرتے ہیں تو وہ نظریہ ایک خاص قسم کے سیاسی‘ اخلاقی‘ اقتصادی‘ علمی ‘ قانونی اور اجتماعی حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ حالات چونکہ حسن و جمال سے عاری ہوتے ہیں ہم کچھ عرصہ کے بعد ان کی نادرست اور غیر تسلی بخش کیفیت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جونہی کہ یہ صورت پیش آتی ہے ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ نظریہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اور جو ان کو وجود میں لانے کا سبب ہواہے‘غلط اور ناتسلی بخش ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہماری محبت فوراً نفرت میں بدل جاتی ہے اور ہم اسے تبدیل کرنے کے لیے زورشور سے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس جدوجہد کانتیجہ ایک سیاسی اور اجتماعی انقلاب کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور پھر ایک نئے نظریہ کی حکومت قائم ہوتی ہے اور ہم اپنی ساری زندگی کو یعنی اپنی سیاست ‘اپنے اخلاق‘ اپنے قانون‘ اپنی اقتصادیات اور اپنے علمی نقطۂ نظر کو بدل کر اس نظریہ کے مطابق کر دیتے ہیں۔
غلط انتخاب کا نتیجہ
اگر جدید نظریہ جو اس طرح وجود میں آئے پھر غلط ہو یعنی وہ خدا کا آدرش نہ ہو تو گو ہم اس بات کی احتیاط کر لیتے ہیں کہ اس میں وہ نقائص موجود نہ ہوں جو پہلے نظریہ میں موجود تھے اور جن کی وجہ سے وہ ناتسلی بخش اور غلط قرار دے کر بدل دیا گیا تھا۔ تاہم ان نقائص کی بجائے ہم اپنے لاشعور کے جذبۂ حسن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس جدید نظریہ کے اندر بعض اور نقائص داخل کر دیتے ہیںجو کچھ عرصہ کے بعد پھر ہماری نفرت اور پریشانی کا موجب ہوتے ہیں۔ صرف وہی نظریہ جس کے اندر حسن حقیقی کی جملہ صفات موجود ہوں ایسا صحیح اور کامل نظریہ ہو سکتا ہے جو ہمیں مستقل اور مکمل طور پر مطمئن کر سکے۔ جب اس قسم کے نظریہ کی محبت کسی جماعت کے ہر فرد کے دل پر فی الواقع چھا جائے تو پھر اس جماعت کے اندر زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ناگوار اور ناتسلی بخش حالات پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی سیاسی یا اجتماعی انقلابات رونما ہو سکتے ہیں۔
ایک اور دلیل
مارکس کا یہ عقیدہ کہ نظریات سماج کے معاشی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں‘ اس لیے بھی غلط ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر دو جماعتوں یا قوموں کے معاشی حالات ایک جیسے ہوں تو ان کے نظریات یعنی سیاست‘ ہنر‘ فلسفہ‘ مذہب اور اخلاق کے متعلق ان کے خیالات بھی ایک جیسے ہوں گے۔ حالانکہ ایک ہی قسم کے معاشی حالات کے پہلو بہ پہلو مختلف قسم کے سیاسی‘ اخلاقی‘ مذہبی یا علمی نظریات کا ہونا ممکن ہے۔ تاریخ پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ گو بہت سی جماعتیں یا قومیں اپنی تاریخ کے کسی نہ کسی مرحلہ پر ایک ہی قسم کے اقتصادی حالات میںسے گزری ہیں اور ان کا معاشی اور صنعتی نظام ایک ہی رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس زمانہ میں ان کے نظریات ایک دوسرے سے بے حد مختلف تھے۔
حالات اور نظریات کا تعلق
اقتصادی حالات کے ساتھ ہمارے نظریات کا کوئی تعلق ہے تو فقط یہ ہے کہ جب دولت غیر مساوی طور پر اور بے انصافی سے تقسیم ہو رہی ہو تو ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا باعث ہمارا نظریہ ہے۔ لہٰذا ہم غلط نظریہ کو بدل کر صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ نظریہ کی تبدیلی اقتصادی حالات کا نتیجہ ہے تو اصل صورت حال کی کوئی توجیہہ اس سے زیادہ غلط نہیں ہو سکتی ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں نظریہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اقتصادی حالات ہمیشہ ہمارے نظریہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارا نظریہ تسلی بخش ہو گا تو وہ اقتصادی حالات بھی جو اس سے پیدا ہوں گے‘ تسلی بخش ہوں گے۔
ایک اور پہلو
اقتصادی حالات ایک اور طرح سے بھی نظریہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اقتصادی حالات نظریہ کے حصول کی خاطر ہماری جدوجہد میں آسانیاں یا مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اقتصادی ضروریات کو آسانی سے پورا کر رہے ہوں تو ہم نظریہ کی خاطر جدوجہد کرنے کے لیے زیادہ طاقتور اور زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ اگر صورتِ حال اس کے برعکس ہو تو نظریہ کی خاطر ہماری جدوجہد مشکل ہوتی ہے۔ اس صورت میں اقتصادی مشکلات کا حل پیدا کرنا نظریہ کی خاطر ہماری جدوجہد کا پہلا قدم ہوتا ہے۔
چونکہ آدرش ہماری فطرت کا ایک مستقل تقاضا ہے جو جذبۂ حسن سے پیدا ہوتا ہے اور اقتصادی حالات پر موقوف نہیں‘ لہٰذا ہم اس کی خاطر اقتصادی حالات کو بدلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بعض وقت یہ حالات اچھے ہوتے ہیں اور بعض وقت برے اور اس بات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے آدرش کا معیار حسن و کمال کیا ہے اور نیکی‘ صداقت اور حسن کے اوصاف سے کس قدر قریب ہے۔ جب یہ حالات برے اور ناتسلی بخش ہوں تو ہمارا جذبۂ حسن ان کو پرکھتا ہے اور پھر ہم ان کو بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔